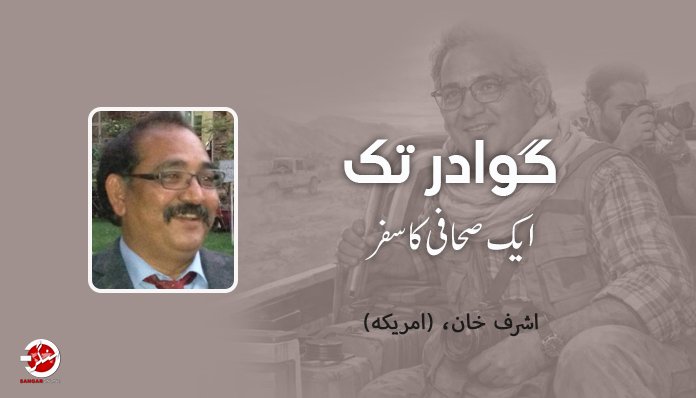میں پاکستان کے اُن چند صحافیوں میں شامل ہوں جنہوں نے گزشتہ پچیس برسوں میں بلوچستان کی تبدیلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ مشاہدہ نہ تو فون کالز پر ، نہ کسی اسٹوڈیو میں تجزیے کرتے ہوئے—بلکہ زمین پر جا کر، راستوں پر، قصبوں میں اور لوگوں کے درمیان رہ کر رپورٹنگ کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔
آنے والی اقساط میں میں اپنی مشاہدات اور ذاتی تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ایسے تجربات جو شاید آپ کے لیے نہ صرف معلوماتی ہوں بلکہ دلچسپی اور فہم کا باعث بھی بنیں۔سب سے پہلے، میں نے 2001 میں پہلی بار بلوچستان کا سفر کیا، جو ایک نہایت مہم جوئی سے بھرپور اور یادگار تجربہ ثابت ہوا۔ اُس وقت میں ابھی ابھی ایک بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی میں تعینات ہوا تھا۔ یہ ہر عملی صحافی کا خواب ہوتا ہے، کیونکہ ایسی ایجنسی میں کام کرتے ہوئے رپورٹر کو وسیع تر سطح پر رپورٹنگ کا موقع ملتا ہے۔
اسی دوران ہمیں اطلاع ملی کہ ہماری حریف بین الاقوامی خبر ایجنسی کی ایک ٹیم گوادر جا رہی ہے۔ ہم نے فوراً اپنے ایڈیٹرز کو مطلع کیا۔ اُن کی ہدایت واضح تھی:
“تم بھی گوادر جاؤ۔”
یہاں ذرا پس منظر واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نائن الیون ہو چکا تھا۔ اُس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امریکہ افغانستان پر حملہ کرے گا، مگر صورتحال یہ واضح نہیں تھی کہ یہ حملہ کب اور کس طرح کیا جائے گا۔ اسی غیر یقینی فضا کے دوران ملک بھر میں امریکہ کے خلاف بھرپور مظاہرے شروع ہو چکے تھے۔ پاکستان بھر میں، خصوصاً کراچی، پشاور اور دیگر بڑے شہروں میں، بڑے پیمانے پر جلسے جلوس ہو رہے تھے،زیادہ تر مذہبی جماعتوں کے، جن میں جمعیت علمائے اسلام (جے یو آئی) سرِفہرست تھی۔ ان مظاہروں کو غیر معمولی کوریج اس لیے بھی مل رہی تھی کہ جے یو آئی طالبان کی کھلی حامی سمجھی جاتی تھی اور اس وقت طالبان حکومت اور القاعدہ دونوں—امریکہ کے براہِ راست اہداف سمجھے جا رہے تھے۔ ۔
اُس وقت یہ تاثر عام تھا کہ شاید پاکستان بھی اگلا ہدف ہو—کیونکہ القاعدہ نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان میں بھی اپنا ایک وسیع نیٹ ورک رکھتی تھی۔ مجموعی طور پر ملک میں ایک جنگی فضا قائم ہو چکی تھی۔
اس پس منظر میں گوادر کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ وہ اُس وقت محض ایک چھوٹا سا ماہی گیر قصبہ تھا،نہ بندرگاہ، نہ ساحلی شاہراہ، اور نہ ہی وہ اسٹریٹجک حیثیت جو آج اسے حاصل ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی حیران کن تھی کہ ایسے حالات میں گوادر جانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔
بہرحال، ہمیں اگلے دن گوادر روانہ ہونا تھا۔ صبح گیارہ بجے گوادر کی فلائٹ تھی۔ میں اور میرا فوٹوگرافر ساتھی وقت پر ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں ہماری ملاقات حریف خبر ایجنسی کی ٹیم سے بھی ہوئی جو ذاتی طور پر ہمارے دوست ہی تھے، مگر پیشہ ورانہ تقاضوں کے مطابق نہ وہ ہمیں اپنی اسائنمنٹ کی تفصیلات بتا سکتے تھے اور نہ ہم اُن سے زیادہ سوال کر سکتے تھے۔
اُن کی فلائٹ بک تھی، ہماری نہیں۔ بہت کوششوں کے باوجود ہمیں اُس فلائٹ میں جگہ نہ مل سکی۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے اور ہم ایئرپورٹ پر کھڑے جہاز کو اڑتے دیکھتے رہ گئے۔
بین الاقوامی خبر ایجنسیوں کے مسابقتی ماحول میں یہ ایک انتہائی نازک صورتِ حال ہوتی ہے۔ اگر آپ کی حریف ایجنسی زمینی رپورٹ فائل کر دے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو یہ ایک پیشہ ورانہ ناکامی تصور کی جاتی ہے۔ اس لیے “فلائٹ نہ ملنا” ایڈیٹر کے سامنے کوئی قابلِ قبول عذر نہیں ہوتا۔
ہم دونوں نے وہیں ایئرپورٹ پر بے چینی کے عالم میں متبادل راستے تلاش کرنا شروع کیے۔ اُس وقت کراچی سے گوادر بذریعہ سڑک سفر نہایت مشکل اور خطرناک تھا۔ مکران کوسٹل ہائی وے کا دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا۔
ہم نے ایئرپورٹ پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی اور فلائٹ دستیاب ہے؟ تب ہمیں معلوم ہوا کہ دوپہر دو بجے پنجگور کے لیے ایک پرواز روانہ ہو رہی ہے، اور وہاں سے تقریباً چار گھنٹے کے زمینی سفر کے بعد گوادر پہنچا جا سکتا ہے۔
بڑی تگ و دو کے بعد آخرکار ہم نے اُس فلائٹ میں دو نشستیں حاصل کر لیں اور ایئرپورٹ پر ہی پرواز کے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اُس زمانے میں بلوچستان کے لیے زیادہ تر فوکر (Fokker) طیارے استعمال ہوتے تھے۔ یہ نہایت مضبوط مگر خاصے پرانے جہاز تھے، جن کا استعمال پہلی اور دوسری جنگِ عظیم کے دوران بھی ہو چکا تھا، اور اب یہ اپنی آخری نسلوں میں شمار ہوتے تھے۔
ان جہازوں کا حجم چھوٹا ہوتا تھا، اسی لیے انہیں ٹرمینل سے نہیں لگایا جاتا تھا۔ مسافروں کو ایک بس میں سوار کر کے ٹارمک تک لے جایا جاتا، جہاں سیڑھیوں کے ذریعے جہاز میں داخل ہونا پڑتا تھا۔
جب ہم بس میں سوار ہوئے تو حسبِ توقع زیادہ تر مسافر بلوچ تھے۔ میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ایک بلوچ مسافر سے میں نے پوچھا:
“پنجگور سے گوادر کا راستہ کتنا ہے؟”
اُس نے بغیر کسی تامل کے انگلیوں پر حساب لگانا شروع کیا۔
“پنجگور سے تربت آٹھ گھنٹے، اور تربت سے گوادر چار گھنٹے کل بارہ گھنٹے۔”
یہ سن کر تو جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں تو ایئرپورٹ پر کسی نے کہا تھا کہ پنجگور سے گوادر محض چار گھنٹے کا سفر ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا، پھر ہم نے خود کو سنبھالا۔
میں نے فوراً اپنے فوٹوگرافر ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہمارا اندازہ تھا کہ ہم شام چار بجے پنجگور پہنچ جائیں گے، اور وہاں سے فوراً کوئی ٹیکسی یا گاڑی کرائے پر لے کر گوادر کی طرف روانہ ہو جائیں گےچاہے پوری رات ہی کیوں نہ لگ جائے۔
اس وقت ہمارے سامنے ایک ہی مقصد تھا:گوادر ہر صورت پہنچنا۔
تقریباً شام چار بجے پنجگور میں لینڈ کیے اور ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ باہر ہم کسی ٹیکسی کی تلاش میں تھے، مگر روایتی ٹیکسیاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ زیادہ تر ڈبل کیبن ٹویوٹا اور اسی قسم کی گاڑیاں کھڑی تھیںبعد میں معلوم ہوا کہ یہی یہاں کی ٹیکسیاں تھیں۔
ہم نے ایک ڈرائیور سے بات کی کہ ہمیں گوادر جانا ہے۔ اس نے صاف جواب دیا کہ وہ خود تو گوادر نہیں جائے گا، البتہ ہمیں شہر تک چھوڑ دے گا، جہاں سے ہم گوادر کے لیے کوئی اور گاڑی کرایے پر لے سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں شہر پہنچا دیاجو دراصل ایک قصبے جیسا ہی تھا۔
وہاں اڈے پر گاڑی والوں سے بات چیت ہوئی۔ وہ خاصے زیادہ پیسے مانگ رہے تھے۔ میں نے یہ بات یوں کہی جیسے میرا وہاں آنا جانا معمول کا حصہ ہو۔ میں نے کہا کہ میں پچھلے ہفتے ہی یہاں آیا تھا اور اتنے پیسے نہیں دیے تھے۔ کچھ بحث کے بعد ایک ڈرائیور راضی ہو گیا۔
ہم نے فوراً کیلے، بسکٹ، پانی اور کچھ دوسری ضروری چیزیں خریدیں، گاڑی میں سامان ٹھونسا، اور گوادر کی طرف روانہ ہو گئے۔
چند ہی منٹ میں وہ چھوٹا سا قصبہ پیچھے رہ گیا اور ہم ایک پتھریلے، کچے راستے پر آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈرائیور نے کہا کہ ڈیزل بھروانا ہے۔ میں نے کہا، “بھروالو۔”
تھوڑی ہی دیر میں اس نے گاڑی ایک ویران بیابان میں بنی ایک جھونپڑی کے باہر روک دی۔ میں نے سوچا شاید کسی جاننے والے کا گھر ہوگا۔ مگر جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر ڈرموں کی قطار نظر آئی۔
اوہ! یہ تو پیٹرول پمپ تھاایرانی پیٹرول اور ڈیزل۔
جیری کینز میں ڈیزل بھرا گیا اور کچھ اضافی بھی ساتھ لے لیا۔ گاڑی پھر چل پڑی بڑے بڑے پتھروں اور بولڈرز کے درمیان سے گزرتی ہوئی۔ جھٹکے اتنے شدید تھے کہ ہمارے سر بار بار گاڑی کی چھت سے ٹکراتے۔
میں نے ڈرائیور سے پوچھا:
“سڑک کب آئے گی؟”
وہ بولا:
“صاحب، یہی سڑک ہے۔”
میں ایک بار پھر اس صدمے کو ہضم کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔
کچھ دیر بعد ہم ایک جگہ رکے اور کسی جھونپڑے نما ہوٹل پر چائے پی۔ چاروں طرف لق و دق پتھریلا میدان، دور چند پہاڑ، اور بیچ میں یہ تنہا سی جھونپڑی۔ وہاں ایک نوجوان ایک نئی نویلی 125 سی سی موٹر سائیکل پر چکر لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ایرانی موٹر سائیکل ہے۔
مجھے ایران سے اسمگلنگ کا سرسری علم تو تھا، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کی معاشی زندگی ایرانی مصنوعات پر چل رہی ہےپہلے ڈیزل، اب موٹر سائیکل۔
ہم پھر آگے بڑھے۔ راستے میں نہ کوئی اور گاڑی، نہ کوئی انسان، نہ درخت، نہ سبزہ—صرف میدان، پتھر اور پہاڑ۔ مجھے یوں لگا جیسے ہم زمین پر نہیں بلکہ مریخ پر سفر کر رہے ہوں۔
رات تقریباً آٹھ بجے ایک اور ایسے ہی ویران مقام پر واقع ہوٹل پر ہم نے کھانا کھایا۔ جھونپڑی کے باہر ایک چٹائی بچھی تھی، ہم اس پر جا بیٹھے۔ ایک لڑکا گھی کے ڈبے سے بنا ہوا پانی کا جگ لے آیا۔ سلاد رکھا گیا، اور ساتھ ہی ایک سونی کا پاکٹ ریڈیو رکھا گیا، جس پر بی بی سی ٹيون تھی۔
کھانے کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہو گئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ پہاڑوں کے سائے تاریکی میں خوف ناک صورتیں اختیار کیے ہوئے تھے۔ پورے سفر میں ہمیں صرف گاڑی کی ہیڈلائٹس کی روشنی میں آگے کا راستہ دکھائی دیتا تھا، جبکہ اردگرد گھپ اندھیرے سے بھی زیادہ اندھیرا تھا۔
نہ جھٹکوں کی وجہ سے سو سکتے تھے، نہ چین سے بیٹھ سکتے تھے۔
رات بارہ یا ایک بجے کے قریب ہم تربت پہنچے۔ شہر بند ہو چکا تھا۔ ایک پیٹرول پمپ پر گاڑی ری فیول کی۔ چائے پی یا نہیںاب یاد نہیں۔ مگر یہ رُکنا ہمارے لیے نعمت تھا، کیونکہ اس وقفے میں ہمیں اپنے تھکے، جھنجھوڑے ہوئے جسم کو کچھ آرام دینے کا موقع ملا۔
پھر ایک بار ہم اسی خلا نما ویرانے میں داخل ہو گئے۔ گھپ اندھیرا، گرد، میدان، پہاڑ۔ رات کے کس پہر میں تھے، معلوم نہیں۔ اچانک ایک جگہ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔
میں نے پوچھا، “کیا ہوا؟”
وہ بولا، “صاحب، چائے پینی ہے۔”
میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھاکوئی ہوٹل نظر نہیں آیا۔ صرف اندھیرا۔ مگر گاڑی کا رکنا پھر بھی نعمت تھا۔ ہم دونوں نیچے اترے۔ اندھیرے میں ایک سمت بڑھے تو میرے پاؤں کسی چٹائی سے ٹکرا گئے۔
آہ!
میں وہیں خود کو اس پر گرا دیا۔ میرے ساتھی نے بھی یہی کیا۔
جیسے ہی میں لیٹا، میری نظر آسمان پر پڑی۔
میں نے ایسا آسمان اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ستارے یوں چمک رہے تھے جیسے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوا جا سکتا ہو۔ ہر ستارہ صاف، واضح، مختلف شکلوں اور نقشوں میںایک جادوئی منظر۔
راستے بھر کی ساری تھکن پل بھر میں ختم ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون سی جگہ تھی، مگر وہ ستاروں سے بھرا آسمان آج تک میرے ذہن سے محو نہیں ہوااور پھر کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملا۔
کچھ دیر بعد وہ عذاب ناک سفر پھر شروع ہو گیا۔ نہ جانے کب غنودگی آ گئی۔ تب مجھے یقین آیا کہ نیند تو شاید سولی پر بھی آ جاتی ہوگی۔
آنکھ کھلی تو گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ باہر وہی اندھیرا، وہی ویرانی۔ مختلف خیالات نے یلغار کی، مگر میں نے سب کو جھٹک دیا اور پھر سو گیا۔
دوبارہ آنکھ کھلی تو گاڑی چل رہی تھی۔ مشرقی افق پر ہلکی سی روشنی نمودار ہو چکی تھی۔ آگے بڑھے تو پو پھٹ گئی۔ دن کی روشنی میں ایک میلوں پر پھیلا ہوا لق و دق میدان سامنے تھا۔
اسی میدان کے بیچ، جہاں حدِ نظر تک کچھ نہ تھا، ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔
میں نے پوچھا، “اب کیا ہوا؟”
وہ بولا، “صاحب، میں کئی سال بعد گوادر آیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بائیں جانا ہے یا دائیں۔”
میں نے دیکھاٹائروں کے نشانات سے کئی راستے بنے ہوئے تھے، مگر کوئی سرا نہیں۔ نہ عمارت، نہ درخت، نہ کھمباکوئی علامت نہیں جو سمت بتا سکے۔
میں خاموش رہا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے اپنی فطری سوجھ بوجھ پر ایک سمت گاڑی موڑ دی۔
کچھ ہی دیر بعد ہمیں چند انسان نظر آئےکچھ لوگ جال اٹھائے جا رہے تھے۔
ہم گوادر پہنچ چکے تھے۔
صبح کے تقریباً چھ بج رہے تھے۔
چودہ گھنٹے کا سفر۔
گوادر۔
مگر سچ یہ تھا کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ
ہم یہاں آخر آئے کیوں ہیں۔
جاری ہے…
یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔
***